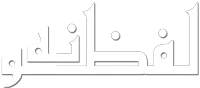تحقیق و تحریر: احمد شیر رانجھا
1917ء کا مشہورِ زمانہ روسی انقلاب بظاہر تو ولادی میر لینن، ٹراٹسکی اور ان کے بالشیوک پارٹی انقلابیوں کی مارکسسٹ تحریک کا نتیجہ نظر آتا ہے، مگر درحقیقت اس انقلاب کی اصل فکری اور سماجی بنیاد وہاں کے مقامی لکھاری نے ہی اپنے ناول، افسانے، کہانی، ڈرامے، سفرنامے اور خود اپنے ذاتی طرزِ عمل کے اندر سے پیدا کی…… جسے لینن اور اس کی سرخ پوش بالشیوک تحریک نے بہت بعد میں اس وقت ’’کیش‘‘ کیا کہ جب لوہا گرم ہوا اور ان لوگوں نے آگے بڑھ کر اس تیار زمین پر اپنا سرخ پھریرا لہرا دیا۔ سو لینن اور اس کی بالشیوک تحریک روسی لکھاری کی لکھی کاوش کا آخری باب سمجھا جائے نہ کہ ابتدا……!
یہ اس معاشرے کی بات ہے کہ جس میں تواتر کے ساتھ عظیم لکھاری اور صاحبانِ قلب پیدا ہوئے اور ان کی روشنی نے ہر شے بدل کر رکھ دی۔ ذرا اندازہ فرمایئے کہ پشکن، گوگول، ٹالسٹائی، ٹرگنیف، چیخوف، دوستووسکی اور میکسم گورکی جیسے ایک سے بڑھ کر ایک حساس اور زندہ قلب لوگ، روس کو نئی کروٹ لینے سے کون روک سکتا تھا! لیکن روسی سرزمین کے گہرے دکھڑے سے پیدا ہونے والے ان عظیم لکھاریوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 19ویں صدی کے اس روسی معاشرے کی ایک تصویر بھی سامنے رکھی جائے کہ جس کے الم ناک اندھیرے میں یہ دردمند لوگ روشن ہوئے۔
19ویں صدی کے روس میں طاقت و اقتدار کا مثلث کچھ یوں تھا کہ سب سے اوپر بادشاہ یعنی ’’زار روس‘‘ (Tsar) اور اس کا ’’شاہی محل‘‘ تھا…… اور اس کے نیچے اس کی مربوط اور بہت سفاک افسر شاہی (Bureaucracy) اور پھر پورے روس کے طول و عرض میں پھیلی بادشاہ کے منظورِ نظر اعزازی امرا و رئیس زادوں (Counts) شاہ زادوں (Princes) اور وسیع جاگیروں کی مالک فوجی اشرفیہ کی فوج ظفر موج جسے ’’جینٹری‘‘ (Gentry) یا بالادست اعلا طبقہ کہا جاتا تھا…… اور پھر ان سب سے نیچے تھر تھر کانپتا وہ بھوکا ننگا، جاہل، گنوار اور ناخواندہ ’’مزہک‘‘ (Muzhik) یا پھر ’’کمی کمین‘‘ طبقہ کہ جس کو سب ’’اوپر والے‘‘ مل کر چوستے اور بھنبھوڑنے تھے۔ یعنی 2 فی صد ’’شاہی‘‘ اشرافیائی طبقہ 98 فی صد زمینی اور انسانی اثاثوں کا مالک تھا اور یہ باطل نظام پشت ہا پشت سے قایم و دایم چلا آتا تھا۔
ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے پورے وسیع و عریض روس کو چھوٹی بڑی ذاتی جاگیروں یا ’’اسٹیٹس‘‘ (Estates) میں تقسیم کرکے شاہ کے منظورِ نظر خاندانوں اور بہت طاقت ور بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ان ’’جاگیروں‘‘ کی ’’الاٹمنٹ‘‘ کا بھی ایک متعین طریقہ تھا کہ یہ زار کے خاص الخاص وفاداروں کو پہلے پہل محدود مدت کے لیے ، لیکن پھر، کامل وفاداری کے صلے میں، مستقل عطا کر دی جاتی تھیں، لیکن ’’زار‘‘ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جب چاہے کسی کو بے دخل کر کے گنگال کر ڈالے۔سونے پر سہاگا یہ کہ اس تمام تر بے رحم شاہی جکڑ بندی کو مذہبی اور روحانی سطع پر، روسی قدامت پرست (Orthodox) چرچ کی مکمل آشیرباد حاصل تھی اور ہر شے بے لچک شخصی قانون اور مذہب کی زنجیروں میں جکڑی تھی۔
لیکن دھرتی کا رزق چوں کہ چند ہاتھوں میں محدود اور صرف چند تجوریوں میں ہی بھرا چلا جاتا تھا، سو دھرتی پر بھوک، افلاس اور انسانی کس مہ پرسی کا پہرہ تھا اور اس کے بھیانک اثرات ہر طرف نظر آتے تھے۔ مثلاً تاحدِ نگاہ پھیلی خوفناک برف پوش روسی وسعتوں میں آپ کو جابجا بھوکے ننگے، بے یار و مدد گار انسانوں (Tramps) کی خستہ حال ٹولیاں، خوراک اور پناہ کی تلاش میں اِدھر اُدھر بھٹکتی نظر آتی تھیں…… اور کوئی ان کا پرسانِ حال نہ تھا۔
دنیائے ادب کے عظیم ترین ناول ’’ماں‘‘ کا مصنف میکسم گورکی اسی خالی پیٹ آوارہ گردی کی سفاک ٹھوکروں میں ہی پلا بڑھا تھا…… اور لڑکپن سے لے کر جوانی تک روس کے طول و عرض میں رُلتا جب اپنے ان تجربات کو بالآخر اپنی تحریروں میں کھولتا ہے، تو رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کی کئی جلدوں پر مشتمل خود نوشت ’’میری درس گاہیں‘‘ یا پھر "My Universities” انہی اندھی، بھوکی، ٹھوکروں کی روداد ہے…… اور روس کی اصل اندرونی کہانی پیش کرتی ہے۔
اسی طرح عظیم لکھاری اور زار کی بخشی ایک وسیع جاگیر کے مالک، کاونٹ لیو ٹالسٹائی، اپنی خاندانی امارت کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی نانی اپنی آبائی جاگیر میں کھمبیاں چننے کے لیے جب جنگل کی طرف نکلتی تھیں، تو ان کی دو پہیوں والی بگھی کے آگے دو نوکر "Muzhiks” جوتے جاتے تھے جو بگٹٹ بھاگتے اپنے آپ کو کوئی چھوٹا موٹا گھوڑا ہی تصور کرتے تھے۔
ملک کی اکثریتی آبادی ہماری طرح شہروں کی بجائے دیہات میں رہتی تھی اور کوڑی کوڑی کی محتاج تھی۔ بہرحال دیہاتوں کی خوف ناک غربت اور کس مہ پرسی کے برعکس روسی شہر اپنے محلات، عشرت کدوں، مارکیٹوں، ڈانس ہالوں، پارٹیوں اور شراب خانوں میں اپنے کسی ہم عصر یورپی شہر، لندن، پیرس یا برلن سے کسی بھی طرح کم نہ تھے، مگر فرق صرف یہ تھا کہ لندن اور پیرس تو اپنی جدید صنعتی ترقی اور نو آبادیاتی دولتوں سے جگمگا کر اوپر ابھرے تھے، مگر روسی شہر اپنے انسانوں اور دیہاتوں کا خون نچوڑ کر ہی یہ چہل پہل دکھاتے تھے…… لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس عالم میں جب بھی کوئی روسی لکھاری لکھنے کو بے تاب ہوتا، تو بجائے شہر میں بیٹھے رہنے کے اپنے دیہاتی خرابے کا رُخ کرتا، اپنی اصل کہانی ڈھونڈ لینے کو اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کا تعلق کھاتے پیتے گھرانوں یا پھر ’’جینٹری‘‘ سے تھا اور ان کا یوں اپنے عام آدمی کی حالت پر تڑپ اُٹھنا اور پھر خود کو اپنے اشرافیائی طبقے سے الگ کر کے نچلے پسے ہوئے طبقات کی طرف متوجہ ہو جانا ناقابل فہم تھا۔
لیکن ان کی تحریریں ہمیں اس سوال کا جواب مہیا کرتی ہیں کہ ان کو اپنی دھرتی کے کرب نے بے حال کر کے رکھ دیا تھا اور ضمیر کے کچوکوں نے ان پر ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ کی پارٹیاں حرام کر ڈالی تھیں۔
اس سلسلے میں ٹالسٹائی کی مثال سب سے حیرت انگیز ہے کہ وہ ’’کاونٹ‘‘ یعنی سرکاری سطح پر، رئیس زادے کا اعلا سوشل درجہ رکھتے تھے، لیکن ایک دن اچانک اپنے جاگیرداری ٹھاٹھ باٹھ اور ماسکو کی شہری چمک دمک سے یوں دل برداشتہ ہوئے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ماسکو کے قریب واقع اپنی آبائی جاگیر ’’یسنایا پولیآنا‘‘ میں مستقل رہایش پذیر ہوئے اور ایک عام دہقان کی سی زندگی گزارنے لگے۔ وہ بجائے امارت اور ٹھاٹھ باٹھ کے…… سادگی اور فقر میں لذت محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ پہروں اپنے مفلوک الحال مزارعوں کے ساتھ کسی شاہ بلوط کی گھنی چھاؤں میں بیٹھے ان کی کہانیاں سنتے۔ ان کے بچوں کو پڑھاتے۔ اپنا جوتا اور لباس خود مرمت کر لیتے اور راتوں کو جاگ کر اپنی خواب گاہ میں خاموش بیٹھے ’’وار اینڈ پیس‘‘ اور ’’اینا کرینینا‘‘ جیسی اپنی شہرہ آفاق کتابوں پر کام کرتے۔ حالاں کہ غریب کو گلے لگانے کی پاداش میں انہوں نے خانگی سطح پر اپنی امیر طبع بیوی کی بے وفائی اور اولاد کی لاتعلقی کا گہرا چرکا بھی سہا…… مگر وہ اپنے ذاتی دکھ کو روس کے عظیم تر دکھ کے اندر سمو کر اور ایک نیا سویرا اپنی دھرتی کو عطا کر کے ہی واصل بحق ہوئے۔ بس ان کی طرح ہر کوئی تازہ موضوعات کے لیے ’’کنٹری‘‘ یا پھر دیہاتی علاقوں کا ہی رُخ کرتا تھا اور ایک روایت سی بن گئی تھی کہ اگر روس کو سمجھنا ہے، تو روس کے دیہات کو سمجھو۔ وہاں اپنے دیہاتوں میں وہ ہفتوں بلکہ مہینوں قیام کرتے۔ اپنا مواد سمیٹتے اور پھر واپس لوٹ کر اس قیمتی خام مال سے انوکھے شاہ کار تراشتے۔
روس کا دکھ نتھرتا گیا۔ اس کا لکھاری کام کرتا گیا۔ حتی کہ لینن اور ٹراٹسکی کے پُرجوش انقلابی دستوں نے اپنے لکھاری کی تیار کردہ زمین پر 1917ء کے عظیم انقلاب کی فصل بو ڈالی۔ اس وقت کا کوئی بھی روسی ناول یا فن پارہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو کچھ بھی مصنوعی یا صرف سٹڈی میں بیٹھ کر لکھا گیا نظر نہ آئے گا۔ سب کچھ زندگی کی سچی اور زندہ دھڑکن سے ابھرا ہے۔ اور تو اور ’’ٹرگنیف‘‘ (Ivan Turgeniv) جیسا نفاست پسند اور خوش پوش شہری لکھاری بھی اپنی مٹی یا پھر اصلیت میں اترنے کے لیے دیہات کی طرف ہی متوجہ ہوا اور اس کی شہرہ آفاق تصنیف "A Hunter’s Sketches” روس کی دیہاتی معاشرت اور اس کے گہرے اندرونی کرب کی لازوال تصویر بن کر آج بھی ہر طرف چھائی ہے۔ وہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، ایک بے فکر شکاری کی صورت گھومتا پھرا اور اپنی دھرتی کے درد کو ریکارڈ کرتا رہا اور پھر اس کے گہرے، میٹھے لفظ نے کتاب میں ڈھل کر دنیا کو ہلا ڈالا۔
دوستووسکی جیسے لازوال لکھاری نے بھی باقاعدہ ایک لمبا عرصہ زار شاہی کے بیگار کیمپوں اور سائبیریا کے برفانی عقوبت خانوں میں قید تنہائی کاٹ کر اپنے سچے افکار کی سزا پائی۔ وہ اپنے بدقسمت انسان کی غربت و افلاس اور گہری نفسیاتی کس مہ پرسی کا دکھڑا لکھتا تھا اور کچھ اتنا ڈوب کر لکھتا تھا کہ آج کا جدید علم نفسیات اور فلسفہ اس سے جلا پاتا ہے۔
لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے لکھاری کے لیے اس تمام تر بات کے اندر سے کوئی نیا رستہ نکلتا ہے؟ بھلا کب تک وہ اپنی پندرہ فی صد محدود حقیقت کو ہی اپنی کُل حقیقت سمجھ کر ہمیں اُلو بناتا رہے گا۔
…………………………………….
لفظونہ انتظامیہ کا لکھاری یا نیچے ہونے والی گفتگو سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ بھی اپنی تحریر شائع کروانا چاہتے ہیں، تو اسے اپنی پاسپورٹ سائز تصویر، مکمل نام، فون نمبر، فیس بُک آئی ڈی اور اپنے مختصر تعارف کے ساتھ editorlafzuna@gmail.com یا amjadalisahaab@gmail.com پر اِی میل کر دیجیے۔ تحریر شائع کرنے کا فیصلہ ایڈیٹوریل بورڈ کرے گا۔