یہ 2002ء کی بات ہے۔ دلہ زاک روڑ پشاور تب اتنا آباد نہیں تھا، مگر فلیٹس کے سلسلے تعمیر ہو رہے تھے۔ روزگار کے سلسلے میں، مَیں بھی پشاور میں مقیم تھا۔ وہ انتہائی کٹھن اور دل برداشتہ دور تھا۔ تنہائی اور بے بسی میں سوات ہی سے میرا ایک ساتھی ’’تلک راج‘‘ میرا فلیٹ میٹ تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تمام باتیں کرچکے تھے اور ایک دوسرے سے بے زاری عروج پر تھی۔ چوں کہ چھوٹے شہروں سے لوگوں کی آمد مسلسل تھی اور سہ منزلہ چہار منزلہ عمارتوں میں بھرے پڑے خوابوں کا پیچھا کرنے کچھ لوگ مع خاندان بھی بسیرا کیے ہوئے تھے۔ گاہک بہت تھے، رہایش محدود تھی، اس لیے نچلی منازل پر سنگل اور اوپر خاندان والوں کو رکھا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد خاندانوں اور مالک کو ہم جیسے قلاش، بے ضرر اور نیم مردہ قسم لوگوں کے کردار کا یقین ہوا، تو ہمیں ترقی دے کر فیملی والی منزل پر پھینک کر ہمارے فلیٹ کو زیادہ کرائے پر کسی اور کو چڑھادیا۔
ہم نے رسمی سا احتجاج کیا، مگر نکالے جانے کے خوف سے خاموش ہوکر دیوار کی طرف منھ کرکے کتاب پڑھتے یا انقلاب لانے کے خواب دیکھتے، جب کہ تلک راج اپنے ساتھ لڈو کھیلتے کھیلتے سو جاتا، یا کام میں مصروف ہوتا۔
اسی دوران میں ایک تبدیلی آئی…… دو چھوٹے چھوٹے بچے اُسامہ اور سُمیّا کھیلتے کھیلتے ہمارے فلیٹ میں آجاتے اور پھر مجھے اُن کی عادت سی ہوگئی۔ تلک راج کو کچھ دن اعتراض تھا، مگر پھر وہ بھی عادی ہوگیا، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ عادی تھے۔ بچے کبھی کبھی سو بھی جاتے میرے پاس۔ بچی پشتو اور دری زبان روانی سے بولتی۔ مَیں بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی فارسی آزماتا، وہ بہت خوش ہوتی اور معصومیت میں کہتی فارسی بہت پیاری ہے، جیسے پانی کی طرح۔ مَیں پوچھتا: ’’خانہ شما کجا است‘‘، ’’مادر شما کجا است‘‘، ’’امروز سردی است‘‘ اور اس طرح کے کچھ اور جملے۔ وہ جواب دے کر شرماتی اور کہتی میری زبان آپ کی زبان سے سخت ہے۔
ایسے ہی کسی دن مجھے دیر سے مردان جانا ہوا اور جب زیادہ دیر ہوئی، تو وہی ٹھہر گیا۔ صبح 8 بجے ٹھکانے پر پہنچا، تو تلک راج نے کہا کہ بچوں کی ماں کو کسی نے گولی مار دی ہے اور اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ مَیں نے دوڑ کر اُن کے فلیٹ کی طرف دیکھا، تو وہاں تالا لگا تھا۔ تلک راج نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ ہسپتال میں ہیں۔ میری میٹنگ تھی، مگر پورا دن چشمِ تصور میں بچے گھومتے رہے۔ شام کو واپس آیا، تو فلیٹس کا سب سے باتونی شخص ملا اور بڑھا چڑھا کر کہا کہ کس طرح اجرتی قاتل آئے تھے۔ چوں کہ اُن کے بچے ہمارے ہاں آتے ہیں، اس لیے ہم بھی مبینہ طور پر اگلا شکار ہوسکتے ہیں۔ اس پر تلک راج نے سقراط کی طرح بھنویں سکیڑ دیں اور نتھنوں نے پھیپڑوں کی ساری ہوا نکال کر تائید کی، مگر زبان نہیں ہلائی۔
باتونی شخص نے ماحول کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ’’یو ٹرن‘‘ لیا اور میری انسان دوستی پر مجھے نشانِ حیدر دیا اور اصل بات بتائی کہ فلیٹس کی کمیونٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہسپتال جائیں گے اور اپنی ہم دردی کا اظہار کریں گے۔ رات کو ہم ایک جلوس لے کر ہسپتال پہنچے، تو سہمے ہوئے بچے دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ اُن کی والدہ سے مختصر ملاقات ہوئی، اُنھوں نے میرے ہسپتال آنے اور خصوصاً بچوں سے پیار کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ گولی کان کے اوپر اب بھی پھنسی ہوئی تھی۔ باقی زخموں پر پٹیاں تھیں۔
کچھ دن بعد وہ ہسپتال سے خارج ہوکر آئے، تب مَیں نکل کر جانے لگا تھا۔ دونوں بچے آئے۔ اُن کو دیکھ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اُنھوں نے کہا کہ امی بلا رہی ہیں۔ مَیں اُلجھ کر چل پڑا۔ طبیعت پوچھی، اُنھوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اُن کی روزانہ پٹی تبدیل کرنے کا مشورہ ہے۔ اس لیے مَیں اُن کی خدمت کا بیڑا اُٹھاؤں۔ مَیں نے بعد از احترام کہا کہ اول تو مَیں اس کام کا ماہر نہیں۔ دوم، مَیں کم زور دِل شخص ہوں۔ خون اور زخم کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ میری بے ساختہ سی بات، بالفاظِ دیگر انکار سن کر وہ اتنا بے ساختہ ہنسیں کہ اُن کو باقاعدہ تکلیف ہوئی اور درد سے کراہنے لگیں۔ مَیں شرمندہ قباچہ یہ کَہ کر کہ پٹی شام ہی کو بدلنی ہے۔ سو میرے پاس ایک لڑکا ہے، جو ماہر کمپاؤنڈر رہ چکا ہے۔ یہ ڈیوٹی اُس کے ذمے لگاتا ہوں۔ اُن کی طرف سے شکریہ کا لفظ سن کر مَیں گولی کی سی تیزی سے نکل آیا۔
آفس جاکر منظور کو مَیں نے مدد کے لیے کہا، تو اُس نے کہا: ’’قربان جاؤں سر! مَیں حاضر، لیکن یہ پولیس کیس ہے اور صرف ہسپتال ہی میں پٹی ہوسکتی ہے۔ کیوں کہ ہسپتال میں گواہی بھی دینا ہوگی۔‘‘
شام کو مَیں شرمندہ شرمندہ پہنچا۔ وہ منتظر تھے۔ مَیں روشنی کیے بغیر ہی کمرے میں گیا۔ فوراً ہی بچے پہنچے اور کہا: ’’امی منتظر ہے۔‘‘ معاً مجھے اکیلا دیکھ کر مایوس بھی ہوئے۔ مَیں بوجھل قدموں کے ساتھ اُن کے فلیٹ تک گویا ایک صدی میں پہنچا۔ اُنھوں نے میرے چہرے پر ہی جیسے پڑھ لیا تھا۔ ہلکی سی وضاحت پر بول اُٹھی، ’’گویا ہسپتال جانا ہی پڑے گا……! کیا آپ ایک رکشہ اندر تک لے آئیں گے، کیوں کہ یوں باہر سڑک پر رکشے کا انتظار مناسب نہیں لگتا۔‘‘
مَیں فوراً راضی ہوا۔ اُنھیں رکشے میں بٹھاکر میں خوشی اور مایوسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آکر بستر پر ڈھیر ہوگیا۔ وہ کب واپس آئی، پتا ہی نہیں چلا۔ اُس دن میں اکیلا تھا۔ تمام روشنیاں گُل کیے کمرے مَیں خاموش لیٹا تھا۔ پتا نہیں بچے آئے بھی ہوں گے یا نہیں!
پھر اس کے بعد بچے میری طرف آنا کم ہوئے۔ اُن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن بچے اچانک دوبارہ آئے اور کہا: ’’آپ کو امی بلا رہی ہیں!‘‘
مَیں گیا، تو کہنے لگیں، ’’بچے آپ کی طرف آنے کی ضد کرتے ہیں، مگر مجھے گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ آپ کو بُرا نہ لگے، تو بچوں کو زیادہ پیار نہ دیں۔ بس میرے فلیٹ کے آگے کچھ لمحے دن میں اُن کے ساتھ گزار لیا کریں، تاکہ میری تنہائی بھی نہ رہے اور گھبراہٹ بھی نہ ہو۔ یوں اُن کی خوشی کا سامان بھی ہوگا۔‘‘
اس کے بعد چند دن کھلونا بن کر مَیں اُن بچوں کو لبھاتا رہا۔ وہ چلنے کے لائق ہوئیں، تو ساتھ آکے بیٹھ جاتیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی جب پتا چلا کہ وہ شاعری کرتی ہیں اور سریلی آواز کی مالک بھی ہیں۔ اچھی دوستی ہوگئی۔ وہ کم پڑھی لکھی تھیں، مگر مشاہدہ بلا کا رکھتی تھیں۔ مرد ذات سے شدید نفرت کرتی تھیں۔ جب اُن کو پتا چلا کہ مَیں شاعری پڑھنے اور موسیقی سننے میں دل چسپی رکھتا ہوں، تو بہت خوش ہوئیں۔ ایک دن اُنھوں نے عجیب فرمایش کی کہ ’’میری زندگی کی کہانی لکھ دو۔‘‘
یہ سن کر مَیں بڑا حیران ہوا۔ اُنھیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مَیں کوئی لکھاری نہیں ہوں۔ اُنھوں نے فوراً کہا: ’’مَیں نے کون سی فلم بنوانی ہے!‘‘
یوں مَیں جو اُن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اُن کی کہانی لکھنے لگا۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:
میرا نام ایمن ہے۔ ہم سید ہیں اور دیر کے علاقے واڑئی کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ اگر کسی شخص سے مَیں نے محبت کی ہے، تو وہ میرے والد (مرحوم) تھے، جو میری ہر تمنا، ہر آرزو پوری کرتے تھے۔ اُن کا انتقال ہوا، تو میری زندگی میں اندھیرا ہوگیا۔ میرے خواب ٹوٹ گئے اور مَیں ’’بہت اہم‘‘ سے ’’قطعی غیر اہم‘‘ ہوگئی۔ میرے بھائیوں کے لیے مَیں بوجھ تھی۔ ابھی کم عمر ہی تھی کہ اُنھوں نے ایک بڑے عمر کے افغانی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے معلوم ہوا کہ مجھے بیچ دیا گیا ہے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، مگر اُن کی شخصیت بالکل عجیب سی تھی۔ اُن کا گنجا سر، بڑی عمر اور غیر جذباتی انداز مجھے سخت کھٹکتا۔ وہ مال دار آدمی تھے۔ مجھے اچھا گھر لے کر دیا، خوب صورت فرنچائز اور جیم سٹون کا کاروبار کرتے تھے۔ میرا پاسپورٹ بنواکر دبئی، بنکاک، ہانگ کانگ، انڈیا اور کئی ممالک ساتھ لے کر گئے۔ ان کے بارے میں اکثر لوگ کہتے کہ یہ آپ کے باپ لگتے نہیں۔ وہ بھی ہنس کے جواباً کہتے: ’’اس لیے کہ مَیں ان کا شوہر ہوں۔‘‘
مجھے عجیب لگتا۔ مَیں پشتو بولتی۔ وہ فارسی بان تھے، مگر مَیں نے سمجھوتا کرلیا۔ فارسی بھی آہستہ آہستہ سمجھنے لگ گئی۔ بولنا بھی شروع کر دیا۔ مجموعی طور پر مَیں مطمئن تھی میرے بھائیوں پر اکرامات کی بارش تھی وہ اور زیادہ خوش اور مطمئن تھے۔
ایک دن میرے شوہر ملک سے باہر جانے لگے، تو مجھے میکے چھوڑ دیا۔ مَیں ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ بچی سات سال کی ہوگئی تھی اور بیٹا چند دن کا تھا۔ چند دن بعد میرے سسرال کی پڑوسی ایک خاتون میرے میکے آئی اور کہا کہ تم یہاں ہو، تمھارے گھر پر کوئی خاتون ہے شاید، اور تمھارے شوہر بھی۔ ہم سب بے اختیار ہنس دیے اور کہا کہ وہ ملک سے باہر ہیں۔ اُس کے اصرار پر تشویش ہوئی، تو سب چل دیے۔ وہاں پہنچے، تو دیکھا کہ میرے شوہر بنیان پہنے صحن میں لیٹے تھے اور میری نند کی نند کپڑے سکھانے کے لیے پھیلا رہی تھی اور وہ پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ بن بیاہی نوخیز لڑکی اور میرا سرد مہر شوہر فارسی کا کوئی قصیدہ گا رہے تھے۔ مَیں نے آسمان سر پر اُٹھا لیا۔ میرے خاوند نے بڑی منت سماجت کی۔ سب نے واسطے دیے، مگر مَیں نے کہا کہ مجھے طلاق دو۔ سب کی منتیں اور سمجھانے کا عمل مَیں نے یک سر مسترد کردیا۔
شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ مَیں ایک عورت ہوں…… بالکل سامان کی طرح غیر اہم اور بے معنی۔ مجھے جذباتی ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اُصول کی بات مجھے زیب نہیں دیتی۔ انسانیت میں میرا کوئی شمار نہیں۔
میرے شوہر نے رو رو کر مجھے طلاق دی، حق مہر دیا اور گھر کا تمام سامان بھی دے دیا۔ مکان کرائے کا تھا۔ اگلے کئی مہینوں کا کرایہ بھی دے دیا۔ حتیٰ کہ بچوں کو بھی چوم چوم کر گلے لگایا اور جاتے وقت میرے حوالے کر دیا۔ یوں خاموشی کے ساتھ وہ گھر سے کیا، اس ملک ہی سے نکل گیا۔
ایمن نے کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی مجھے میرے گھر لے گئے۔ میری اندر نفرت، حقارت اور ٹھکرائے جانے کے خیالات لاوے کی طرح پک رہے تھے۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عدت کے دن گزر گئے۔ میرے بھائی میرے اردگرد منڈلانے لگے۔ میری کم زور ماں کی رائے بیٹوں کی رائے سے مختلف نہ ہوتی۔ وہ سہمی اور دفاعی انداز میں رہتیں۔ پتا چلا کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میرے تن بدن میں گویا آگ لگ گئی۔ مَیں نے پھر زخموں کو کھرچ کر اُنھیں ہرا کیا اور آسمان سر پر اُٹھا لیا۔ اپنے گھر جاکر خلوت میں رہنے کی بات کی۔ پتا چلا کہ مکان چھوڑا جاچکا ہے۔ ایڈوانس کرایہ واپس لیا جاچکا ہے۔ منحوس سامان بیچا جاچکا ہے۔ اب مَیں اور میرے بچے بوجھ تھے، بہ الفاظِ دیگر سامان تجارت تھے۔ مجھ پر دباو بڑھتا گیا۔ مَیں پہلے ہی اپنے خیالوں کی قید میں تھی۔ اُنھوں نے مجھے عملی طور پر مقید کرلیا۔ باہر نکلنے کا ہر راستہ مسدود کر دیا۔ مَیں تب بھی نہیں سمجھی۔ تب بھی اپنی ہی قید میں تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے درہ آدم خیل کے پاس کہیں کسی کے ہاتھ بیچ دیا، یا وہیں قید کر دیا۔ وہاں تنہائی تھی اور تنگ و تاریک مقفل دروازہ، جو تین ٹائم کھانا پھینکنے کے لیے کھولا جاتا۔ کئی دن وہی قید رہ کر ایک دن دروازہ کھلا پاکر بغیر سمت کا تعین کیے بچوں کے ساتھ بھاگ نکلی۔ معلوم نہیں تھا کہ کہاں بھاگ رہی ہوں اور کہاں پہنچوں گی؟ بس پاگل پن تھا، گرتی پڑتی دوڑتی جا رہی تھی۔ اتنے میں دور سے ایف سی کے کچھ جوان نظر آئے۔ اُن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اُس بیرک پر پہنچی، تو وہ پریشان ہوگئے۔ بچوں کو گود میں لیا اور مَیں روتی رہی۔
اُن جوانوں نے اپنی چادر میرے سر پر ڈالی اور پانی پلایا۔ ایک قلعے میں لے جاکر کچھ کاغذی کارروائی کی اور پشاور کے دارالامان میں کچھ رقم دے کر اُن کے حوالے کردیا۔ دارالامان جاکر پہلی دفعہ مجھے لگا کہ مَیں پہلی اور شاید آخری عورت نہیں ہوں، جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔
میری ابتدائی واجبی سی تعلیم تھی، مگر دنیا کے سفر اور اچھی محافل میں بیٹھنے سے میری تربیت کہیں بہتر ہوئی۔ نشست و برخاست بھی مثالی تھی۔ مشاہدہ اور تجربات نے بھی میری مدد کی۔ ’’ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان‘‘ نے نہ صرف مدد کی، بل کہ تحفظ بھی دیا۔ عاصمہ جہانگیر سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ نہایت قابل اور ہم درد خاتون تھیں۔ اُنھوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ مَیں نے اُن کی زبانی سنا کہ ’’جینے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اسی کو شہادت کہتے ہیں۔ اس پر نادم نہ ہوں۔‘‘
یوں مَیں نے اپنے طور پر زندگی گزارنے کا ارادہ کرلیا۔ یہ مشکل فیصلہ کرنے مَیں داراالامان میں گزرے دنوں اور محترمہ عاصمہ جہانگیر سے ملنے کا بڑا ہاتھ تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ دنیا میں کہیں گوشہ نشین ہوکر باقی زندگی گزار خاموشی سے گزار لوں گی…… مگر جب دنیا کی حقیت دیکھی، تو دنیا اُلٹی نظر آئی۔ مرد ذات سے پہلے بھی نفرت تھی، اس کے بعد شدید تر ہوگئی۔ کسی نے بھی مجھے انسان نہیں سمجھا۔ سب نے مالِ غنیمت سمجھا یا بس شکار۔ کسی نے بیٹی کہا، تو باپ کا رُتبہ گرتے دیکھا۔ کسی نے بہن کَہ کے دلاسہ دیا، تو بھائیوں کے نام سے مزید خوف محسوس ہونے لگا۔ کہیں نوکری کے لیے درخواست دی، تو سی وی اور قابلیت سے زیادہ بستر تک پہنچنے کے دورانیے کی لمبائی پوچھی گئی۔ کسی نے مدد کی کوشش کی، تو بدلے میں عجیب تقاضا کیا گیا۔ اس دوران میں کہیں ایک بھلے شخص نے آپریٹر کی نوکری دے دی۔ واجبی سی تنخواہ اور آنے جانے کا کرایہ ہی ملتا تھا۔ وہ بھلا اس لیے تھا کہ شاید اُس دور سے وہ خود گزر رہا تھا، جہاں جنسی تسکین کی خواہش کم اور اہل و عیال کی معاشی پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ صبح 9 بجے سے شام تک اپنے آپ کو مصروف رکھ کر دوپہر کا کچھ بچا ہوا کھانا، کرائے کے بچائے گئے پیسے اور مستقبل کے اچھے دنوں کا جھوٹ لے کر بچوں کے پاس آتی اور معصوم بچے دروازے کے قفل سے لٹکے نیم خوابیدہ رحمان بادشاہ کی خدائی میں میری طرف دوڑ کر گلے لگ جاتے۔ بھوکے بچے جس دن سیر ہوکر کھانا کھاتے اور کچھ کھانا بچ جاتا، تو خوشی سے میرے آنسو چھلک پڑتے، مگر ایسا کئی کئی ہفتے بعد ہوتا۔ ورنہ کبھی روٹی ختم، تو کبھی سالن ختم……اور ہم تینوں مسکرا کر گلے لگ جاتے۔
دن بغیر کسی خوشی رات، بغیر کسی سکون اور زندگی بغیر کسی سہارے یا امید کی موہوم سی کرن کے گزر رہی تھی۔ ایک شدید ذہنی تناو تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ ایک خوف تھا کہ بھائیوں کا غصہ کتنا بڑھ چکا ہوگا۔ یہ تجسس کہ پیاری ماں کیا محسوس کر رہی ہوگی، بچوں کا والد خوش ہوگا کہ دکھی ہوگا، پچھتا رہا ہوگا کہ مزے اُڑا رہا ہوگا؟ کہیں وہ پلٹ کر بچے نہ لے جائے۔
ایک صبح کام کے لیے نکلی، تو ناقابلِ برداشت شور کے ساتھ گرم سلاخوں کی سلیں جیسے بدن میں پیوست ہوگئیں۔ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور دھڑام سے گرگئی۔ مَیں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک اور شخص کو چہرے پر نفرت کا گہرا نقاب ڈالے ہوئے دیکھا۔ مجھے بچوں کی فکر تھی۔ مَیں زمین پر پڑی رہی اور وہ بھاگ گئے۔ مَیں خون میں لت پت پڑی چیخ رہی تھی۔ راہ چلتوں سے مدد کی درخواست کر رہی تھی اور بنی نوع انسان سہمے آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے میرے گرد جمع ہورہے تھے۔ مَیں کسی گند کی طرح، تعفن کی طرح، کسی سرکس کے جانور کی طرح یا کسی کوٹھے پر بیٹھی رنڈی کی طرح پڑی تھی اور ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق باتیں کر رہا تھا۔
اُس وقت میری مدد کی درخواست کسی دل کو نرم نہیں کر رہی تھی۔ وہاں کھڑا کوئی ذی روح مجھ پر رحم نہیں کر رہا تھا۔ کوئی میرے بچوں کی خاطر مجھے سہارا دینے آگے نہیں آ رہا تھا۔
میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہورہی تھی۔ درد میرے وجود کو توڑ رہا تھا، مگر اتنے آدمیوں کے بیچ شاید ایک بھی انسان نہیں تھا۔
جب مَیں سخت جان نیم بے ہوش ہونے لگی، تو کچھ ہاتھ آگے بڑھے۔ مَیں بے بسی میں اُن ہاتھوں کو اپنے جسم کو تھامتے اور ٹٹولتے محسوس کرسکتی تھی۔ میری آنکھوں، ہاتھوں اور زبانوں نے بری طرح بے پردگی کی۔ مجھے ایک نیم رضامند ڈرائیور کے رکشے میں لاد دیا گیا اور وہ رکشہ دوڑاتا ہوا میرے چاک گریباں میں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ پچھلی سیٹ پر تنہا مَیں زندہ رہنے کی خواہش کے ساتھ تڑپ رہی تھی۔ ’’ایل آر ایچ ہاسپٹل‘‘ کے ایمرجنسی وارڈ میں لاوارث مریض کی طرح وصول ہوئی۔ بعد میں نیرو سرجری وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ کہاں مَیں ہوش میں رہی، کہاں بے ہوش…… مگر ایک گولی کان کے اوپر کھوپڑی میں پیوست رہ گئی، جس کا نکالنا مرنے کی وجہ بن سکتا تھا۔ باقی جسم میں گولیاں گوشت کاٹتے ہوئے نکل گئی تھیں۔ خون زیادہ ضائع ہوا تھا، سو یہ بھی پتا نہ چل سکا کہ مجھے کس کا عطیہ شدہ خون چڑھایا گیا؟ تبھی ہوش آیا جب دونوں بچے سرہانے کھڑے پتا نہیں کب سے رو رہے تھے اور مَیں نقاہت اور خون کے بدبو دار کپڑوں میں گلے نہیں لگا سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ جہاں پٹیاں نہیں تھیں، سر اور چہرے کے وہ حصے چومنے لگے اور مَیں بھی رونے لگی۔ ’’امی نہ مرنا، ہسپتال میں لوگ مر جاتے ہیں۔ مرنا نہیں!‘‘ وہ یہ کہتے ہوئے رو رہے تھے۔
قارئین! مَیں جب یہ کہانی لکھ رہا تھا، تو اس میں بہت تفصیل تھی، ہر درد کی باریکی تھی اور ہر احساس کی گواہی تھی…… مگر مَیں اپنے آنسو کئی بار ضبط کرتے کرتے رہ جاتا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور پتا نہ لگنے دیا کہ کب پچھلا پہر ہوگیا اور نہ یہ احساس ہی رہا کہ بچے مجھ سے لپٹ کر جانے کب سوگئے تھے۔ ایمن اُداسؔ تخلص کے ساتھ یہ کم عمر، خوب صورت اور باذوق لڑکی کتنی بے ترتیبی کا شکار ہے، روشن چہرے کے عقب میں کتنے اندھیرے ہیں…… یہ سوچتے وقت مَیں جھرجھری لے کر سہم سا جاتا۔
ایمن مکمل طور پر ’’اے سیکشول‘‘ (Asexual) تھیں، یا حالات نے اُن کو ایسا کر دیا تھا، یا شاید یہ کہا جاسکے کہ حالات نے اُن کے کردار میں پختگی لے آئی تھی۔ ایسا مَیں نے اُن کی کہانی لکھتے ہوئے، اُن کی شادی شدہ زندگی کے حالات سنتے ہوئے، عملی زندگی میں آنے والے واقعات اور ذاتی مشاہدے، جو ایک پڑوسی اور ہم درد کے طور پر اُن کی کائنات کو وقت دے کر محسوس کیا۔
ایک دن مَیں آیا، تو بچی نے دوڑ کر ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ امی آواز دے رہی ہیں۔ مَیں جب فلیٹ کے دروازے پر پہنچا، تو اُس پر ایک نوٹس نما کاغذ چسپاں تھا، بہ غور جائزہ لیا، تو اُس پر ایک شعر رقم تھا:
دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی
لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے
میرے قدم حیرت اور شرمندگی سے رُک گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے پر آئی۔ زندگی میں دو لوگوں کی بے ساختہ ہنسی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ کاش! مَیں بھی ایسے بے ساختہ ہنس سکتا۔ ایک نعیم بخاری ہیں جب کہ دوسری ایمن اُداسؔ تھیں۔ یہ دونوں ہنستے ہوئے ہنسنے کا حق ادا کرتے تھے۔ ایمن تو نہ رہیں، البتہ نعیم بخاری کو اللہ لمبی زندگی دے، تاکہ وہ اسی بے ساختگی کے ساتھ مسکراتے رہیں۔
ایمن نے اپنی لمبی ناک کو معمول پر لاتے ہوئے میرا حال پوچھا۔ ساتھ ہی دروازے پر چسپاں نوٹس نما کاغذ پر لکھے شعر کو دیکھنے لگی اور پوچھا: ’’کیسا ہے؟‘‘ مَیں نے جواباً کہا کہ ’’یہ تو میری ترجمانی کر رہا ہے۔‘‘ کہنے لگیں: ’’لاحول ولاقوۃ! بدذوق صاحب آج اسے پڑھ رہی تھی۔ اس شعر پر بحث تھی کہ ’کچے‘ اور ’خستہ‘ مکان میں کون سا لفظ مصرعے میں ٹھیک ہے اور اس کا مطب کیا ہے، کتنا وقت لگا اس کو لکھتے ہوئے اور پھر لگانے میں؟ میرا گھر اُن مزاج پرسوں کا مسکن ہوگیا ہے، جو مجھے زخمی حالت میں اُٹھانے پر راضی نہ تھے۔‘‘
مَیں اُن کی اس شٹ اَپ کال کے طریقے پر حیران ہوگیا اور پوچھا: ’’اس شعر پر غور کرنے والے اور سمجھنے والے ہمارے اردگرد کتنے ہوں گے؟‘‘ اُنھوں نے کہا: ’’ایمن اپنا سوچتی ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، اس پر دماغ خراب نہیں کرتی۔‘‘
اگلے چند دنوں میں، مَیں نے فلیٹس کے سب سے باتونی شخص سے اور اس کی طنزیہ نگاہوں سے خود کو بچاتے ہوئے سنا کہ ایمن نے لکھا ہے کہ اس کا فلیٹ پوری بلڈنگ میں ’’خائستہ‘‘ (خوب صورت) ہے۔‘‘
اس موقع پر میرا سر چکرا گیا، مگر گرنے سے پہلے ہی آگے بڑھ گیا۔
ہماری بلڈنگ میں اکلوتا ٹیپ ریکارڈر ایمن کے پاس تھا، یا شاید اس کی آواز باہر نکلتی تھی۔ جہاں مکیش، لتا، جگجیت اور دیگر کی آوازیں اور کچھ فارسی گلوکاروں کی آوازیں سننے کو ملتیں۔ وہ وقت جب وہ جوش میں آکر ٹیپ ریکارڈر کی آواز نیچے کرکے اپنی آواز میں کوئی گیت یا غزل مکمل کرتیں، تو پوچھتیں: ’’بد ذوق صاحب! کیسی تھی غزل؟‘‘ مَیں جواباً کہتا: ’’خود پسند، ماشاء اللہ!‘‘ اور وہ اُسی بے ساختگی سے ہنستیں اور بچے اُس لمحے کے انتظار میں رہتے اور ہنسنے میں ساتھ دیتے۔
قارئین! اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے سلسلے میں، مَیں کئی کئی دن باہر رہتا، مگر واپسی میں کوئی ٹیپ ضرور لاتا۔ جب سہگل کا ٹیپ لاکر دیا، تو بالکل باؤلی ہوگئی۔ نہ نام سنا تھا، نہ آواز، مگر وہ مسحور رہتیں اور بچے ’’قوالی بند کرو‘‘، ’’رونا بند کرو‘‘ کی رٹ لگاتے جاتے۔ وہ اپنی غیر اصلاح شدہ شاعری گا کر ریکارڈ کرتیں، میری واپسی پر مجھے سناتیں، میری ’’آزاد نما‘‘ نظم اپنے انداز میں پڑھ کر ریکارڈنگ مجھے سناتیں اور میرا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ اُن کے ساتھ ہمارا تعلق بہت اچھے دوستوں اور احترام کے ساتھ قائم ہوگیا۔
ایک دفعہ مَیں بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان گیا۔ بڑا خوار ہونے والا سفر تھا۔ اوپر سے ذمے داریوں کا بوجھ اور گھر سے دوری کی فکر۔ ابھی ملاکنڈ سڑک دو رویہ نہیں ہوئی تھی۔ سوات بہت دور تھا اور یوں پلک جھپکتے سوات پشاور آنا جانا اتنا آسان نہ تھا۔ بنوں ڈی آئی خان روڑ اس سے بھی کئی گنا زیادہ تباہی کا شکار تھی۔ مَیں واپس آیا، تو بڑا دل گرفتہ تھا۔ کمرے میں پہنچا۔ دیر تک خود کلامی کے عالم میں رہا۔ اتنے میں بلاوا آگیا۔ ’’بدذوقوں کا چہرا اتنا برا نہیں ہوتا، جتنا بنا کے رکھتے ہیں۔‘‘
مَیں شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مَیں نے کہا کہ مَیں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ مَیں یہ کیریئر ختم کرنے لگا ہوں۔ مَیں واپس جا رہا ہوں۔
اُنھوں نے پوچھا: ’’کیا بنوں میں کچھ زیادہ برا ہوگیا ہے؟‘‘ وہ مذاق کے موڈ میں تھیں…… مگر مَیں نے تاریخی خطاب کیا، جس میں استحصال، سماج، ظلم، افسر، سیٹھ، نچلے طبقے کا سٹاف، مالی بدحالی اور گھریلو پریشانی پر زور دیا۔
وہ کافی سنجیدہ ہوگئیں۔ خاموشی سے سنتی رہیں۔ جب مجھے یقین ہوگیا کہ مَیں نے مطمئن کر دیا ہے، تو وہ بولی: ’’تو کیا پوری دنیا دُکھ اور تکلیف اُٹھا کر کام کرتی ہے؟‘‘
مَیں نے جواباً کہا کہ ’’یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے! (اُس وقت دلہ زاک روڑ پر قریب کوئی ہوٹل، ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں تھا۔ صرف چائے کے ویران سے کھوکھے تھے اور مَیں چائے کا کبھی شوقین نہیں رہا۔) نہ کوئی ڈھنگ کے لوگ ہیں، اوپر سے کپڑے استری کرنے کی جھنجھٹ اور پورا پورا دن بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ کہیں جاکر مشرق اخبار کے کینٹین سے کھانا ملتا ہے، وہ بھی کھانا کم اور جیل کی خوراک زیادہ لگتا ہے۔‘‘
یہ میرے تاریخی خطبے کا دوسرا حصہ تھا اور مَیں واقعی فیصلہ کرچکا تھا۔ مَیں تنگ آگیا تھا اپنی بھاگ دوڑ سے اور کیریئر ختم کرکے کچھ اور کرنے کے بارے میں سنجیدہ تھا۔ اُنھوں نے بہت اعتماد اور اپنائیت سے کہا: ’’دیکھیں! میری بات سنیں۔ مانا کہ آپ بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت تکلیف اُٹھاتے ہیں۔ تنہائی اور بے توجہی کا شکار رہتے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کتنے آزاد ہیں۔ کیا آپ کو کوئی ’رنڈی‘ کہتا ہے؟‘‘ جواباً میرا سر نفی میں ہلا۔ مجھے ایسی بات کی توقع بھی نہیں تھی۔ ’’کیا آپ کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ آپ کے بچے بھوکے نہ سو جائیں؟ کیا آپ کو زندگی کا خوف ہے؟ آپ کے سگے بھائی آپ کو جان سے مارنے کے درپے ہیں؟ کیا آپ کے پاس آگے بڑھنے کی ہمت نہیں؟ کیا آپ اس زندگی سے ڈر گئے ہیں، جس میں تکالیف محض آپ کے ہیولے ہیں، جھوٹ ہے، فرار کی خواہش ہے۔ ایک افسر کا کام یہی ہے کہ وہ تنقید کرے۔ کیا آپ ابھی اپنے ماتحتوں پر نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں، زندگی سے گلہ نہ کریں۔ اس نے تو ابھی کوئی زخم دیے ہی نہیں ہیں آپ کو۔ یہ ہلکی سی گدگدی ہے، اس کو تکلیف نہ سمجھیں۔‘‘
مَیں حیرت سے اُنھیں تکتا اور سنتا رہا۔ میرے ذہن سے وہ بادل چھٹتے رہے، جو خود مَیں نے اپنے سر پر منڈلا رکھے تھے۔ نہ کبھی مَیں نے کپڑے استری کیے۔ نہ کبھی مشرق اخبار کے کینٹین میں زہر نما کھانا کھانے گیا، نہ کبھی بوٹ پالش کیے۔ قہوہ ایمن بہت اچھا بناتی تھیں اور آج بھی مَیں قہوہ پیتا ہوں، بہت پیتا ہوں اور بڑے شوق سے پیتا ہوں، ڈھیر سارا پیتا ہوں۔
ایک دن میں نے ایمن کو کہا کہ پشاور کتنا بورنگ شہر ہے۔ میرے پاس تو یہاں رہنا مجبوری ہے۔ تم کیوں یہاں رہتی ہو؟ تم کہیں بھی رہ سکتی ہو…… اسلام آباد، راولپنڈی، یا لاہور شاید زیادہ آزاد، خود مختار اور محفوظ ہے۔
یہ سنتے ہی وہ ہنسی اور پوچھا کہ ’’پشاور کو کتنا دیکھا ہے؟‘‘ مَیں نے طنزیہ کہا، ’’شاید پشاور کے محکمۂ ڈاک کو اتنا پشاور معلوم نہیں ہوگا، جتنا مجھے معلوم ہے۔ اس کے بازار، گلیاں اور کوچے رکھ چھوڑیں، مجھے تو یہاں کھڈوں تک کا پتا ہے۔‘‘ ایمن کہنے لگیں:’’آپ ٹھیک سمجھ رہے ہوں گے، مگر مَیں کسی دن آپ کو اصل پشاور دِکھاؤں گی۔‘‘
ایک دن چھٹی کے روز وہ مجھے کمپنی باغ لے کے گئی۔ واقعی مَیں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اُس وقت کینٹ میں اپنی مرضی سے آنا جانا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ایمن نے کہا: ’’چلو، مَیں تمھیں آدمی کی ذلالت دکھاتی ہوں۔‘‘ ہم بنچ پر بیٹھے تھے کہ باہر سے ایک مولانا صاحب سائیکل پر گزرتے ہوئے آئے۔ ایمن نے کہا کہ ’’دیکھنا، اس کی عظمت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے!‘‘واقعی وہ صاحب بڑے آرام سے جا رہے تھے، مگر جیسے ہی رنگ دار کپڑوں اور لڑکی (ایمن) پر نظر پڑی، اپنی اوقات پر اُتر آئے۔ وہ سڑک سے تمام توجہ ہٹا کر اور سپیڈ کم کرکے للچائی ہوئی نظروں سے ایمن کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایمن مخصوص انداز میں ہنس رہی تھیں، جس کی گونج ہر طرف تھی۔ مولانا صاحب بھی دانت نکال بیٹھے۔ مَیں تصویر میں تھا ہی نہیں مولانا کے لیے۔
قارئین! ایسا کئی دفعہ ہوا، مَیں نے ایمن کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھا اور دنیا کو بہت مختلف پایا۔
ایک دن شام کو اُنھوں نے پوچھا: ’’وہ آپ کا کالا سوٹ ہے آپ کے پاس؟‘‘ مَیں نے جواباً کہا: ہاں! کیوں تمھیں مرنے کا ارادہ ہے، جو مجھے سیاہ کپڑے پہننے ہیں؟‘‘
کہنے لگیں: ’’نہیں! کسی کو قتل کرنا ہے!‘‘
مَیں نے کہا: ’’پُراَسرار خاتون، بتاؤ! کس کو قتل کرنا ہے؟‘‘
اُنھوں نے جواباً کہا: ’’آج صدر میں ایک پرنٹنگ کمپنی میں انٹرویو دیا ہے۔ وہ ’لاوارث‘ سمجھ کر کچھ اور سوچ رہا ہے۔ آپ نے ساتھ جانا ہے وہ کالا سوٹ پہن کر اور بولنا کچھ بھی نہیں۔‘‘
مَیں نے کہا: ’’اتنی گرمی ہوگئی ہے۔ سوٹ پہن کر جاؤں گا اور خاموش رہوں گا، یقین کرو بالکل جوکر لگوں گا۔‘‘
اُنھوں نے کہا: ’’بد ذوق! آپ کیا لگیں گے، اس پر دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں۔ بس نتائج دیکھتے جائیں!‘‘
اگلے دن ہم وہاں پہنچے۔ وہ پہلے اندر داخل ہوئیں۔ مَیں پیچھے پیچھے ہولیا۔ لوگ کھڑے تھے۔ ہم کرسیوں کے قریب پہنچے۔ ایمن نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا: ’’جناب! یہ ہیں وہ اچھے لوگ اور مہذب ماحول، جہاں آج میری جائننگ ہے۔‘‘
ایمن کے ساتھ اُجلے سوٹ میں ساتھی کو دیکھ کر باقی اندازے اُن لوگوں کے اپنے تھے، مگر ساتھی سمجھ گیا کہ ایمن اسے اپنے نگہبان اور مضبوط بیک گراؤنڈ کو ظاہر کرنے لیے ساتھ لائی ہے۔
مَیں نے وہاں بہترین قہوہ پیا اور اس یقین دہانی پر ایمن کو وہاں چھوڑ کر واپس آگیا کہ یہاں ایمن کو گھر سے زیادہ احترام ملے گا۔ اُنھیں بہن کی طرح رکھا جائے گا۔ اُن کے ساتھ ایک بیٹی کی طرح سلوک ہوگا۔ اور یہی کہ کام کی شوقین خواتین کے لیے یہ ادارہ ہمیشہ سرنگوں رہتا ہے۔
پورا دن مَیں ایمن کے مشاہدے اور انسانی رویوں کے مطالعے پر سوچتا رہا۔ رات کو ملاقات ہوئی، تو بولیں: ’’سوٹ پہننے کا شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ! کل وہ لوگ بہت برے تھے، مگر آج بہت مہذب تھے۔ مجھے ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کا شکریہ!‘‘
ہوٹل ڈی پاپا جی ٹی روڈ مینگورہ کے سامنے ایک مارکیٹ میں لیاقت سے مَیں نے ایک ٹرالی بیگ خریدا۔ کوئی باہر سے لایا تھا۔ واٹر پروف اور شاک پروف قسم کا تھا۔ اُن دِنوں اس کا کوئی زیادہ رواج نہیں تھا۔ اُس کو کھینچتے ہوئے کسی بھی شخصیت کو عجیب سا اعتماد ملتا تھا۔
ایمن نے مینگورہ سے گجرات تک اور ڈیرہ اسماعیل خان تک کا علاقہ میرے ساتھ دیکھا اور لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ایک دن اُنھوں نے پوچھا کہ ’’ایک تقاضا کروں، مایوس تو نہیں کریں گے؟‘‘
مَیں نے جواباً کہا: ’’پیشگی وعدہ نہیں کرسکتا، جواب فٹی فٹی ہے۔‘‘
کچھ سوچ کر کہا: ’’وہ ٹرالی بیگ مجھے دے دیں۔‘‘
مَیں نے کہا: ’’آپ پوچھنے کا کَہ رہی تھیں یا مانگنے کا سوال ہی غلط تھا؟‘‘
وہ کہنے لگیں: ’’بدذوق! ہفتوں سوچنے کے بعد یہ فقرہ رٹا تھا۔‘‘
مجھے وہ بیگ ایمن کو تھماتے ہوئے ہوئے کافی تکلیف ہوئی، مگر 25 روپے کے اعلا کوالٹی کے کئی ٹیپوں کے علاوہ یہ واحد چیز تھی، جو مَیں نے ایمن کو دی۔ بیگ میں ایمن نے اپنی کہانی، جو میری تحریر کردہ تھی، رکھی اور کہا کہ میرے پاس اس سے محفوظ جگہ اور نہیں۔
ایمن نے اس پیش کش کو بھی ناراضی سے ٹکرا دیا تھا، جب میں نے اُنھیں کہا: ’’آپ کے گھر کا کھانا ملتا ہے۔ بے شرم ہوکے کھاتا ہوں۔ سبزی وغیرہ میں ساتھ لیتے ہوئے لایا کروں گا۔‘‘
2004ء میں میری ترقی ہوئی اور مَیں لاہور چلا گیا۔ نئی ذمے داری اور نیا شہر، رابطے کم ہوتے چلے گئے۔ ایمن بھی وہ فلیٹ چھوڑ کر گلبرگ منتقل ہوگئیں۔
ایک دن مَیں لاہور میں تھا۔ ایمن کا فون آیا۔ تب میرا نمبر بھی بدل گیا تھا اور اچھا فون بھی تھا سم والا، فری بھی تھا۔ آواز بہت کم زور تھی۔ ایمن نے دوسری طرف سے آواز دی کہ کئی دن سے بیمار ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خون کی کمی ہے۔ دوا مہنگی ہے۔ اس کا بندوست کردوگے، تو سہولت ہوجائے گی۔‘‘
مَیں نے بے بسی اور بے چارگی محسوس کرتے ہوئے مالی مدد کی پیش کش کی، تو بولی: ’’بدذوق! ہمیشہ بدذوق ہی رہوگے۔ مَیں نے ’سیمپل دوا‘ کی فرمایش کی ہے۔‘‘
اگلے ٹور پر میرے ساتھ اچھی گاڑی تھی۔ مَیں شام کو ایمن سے ملنے گیا۔ باتوں باتوں میں ایمن نے کہا کہ ’’کل اگر وقت مل سکے، تو مجھے تخت بھائی میں رشتے داروں کے گھر لے جاؤ۔ بہت وقت ہوگیا ہے کسی اپنے کو دیکھے ہوئے۔‘‘
مَیں بعد از دوپہر ایمن کو لے کر تخت بھائی گیا، تو اُن کا موڈ بدل گیا اور چارسدہ کے راستے پشاور جانے کا کہا۔ مَیں نے پٹریوں کو کراس کرکے کھیتوں کے درمیان سنسان سڑک پر گاڑی ڈال دی۔ ایمن مایوسی سے نکل کر خوش ہوئیں۔ اَن جان پگڈنڈیوں پر اُنھیں گھماتا گیا۔ وہ دروازے کے شیشے سے سر نکال کر تیز آواز سے بالکل بچوں کی طرح چیختی رہیں۔ واپسی پر اُنھوں نے ایک ٹیپ کا تحفہ دیا۔ ٹیپ ریکارڈر میں رکھ سنا، تو کلام فارسی کا تھا اور آواز ایمن کی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ ٹیپ کافی وقت بعد اسی ریکارڈر میں پھنس گیا اور ہزار کوشش کی مگر اُسے ضائع ہونے سے بچا نہ پایا۔
مَیں ایک دفعہ پشاور آیا، تو ایمن کا فون آیا۔ اُنھوں نے اسلام آباد لے جانے کی خواہش ظاہر کی، جہاں خیبر ٹی وی میں شاید آڈیشنز تھے، مگر میری مصروفیت تھی۔ مَیں نے اگلے کسی دن پر رکھنے کی درخواست کی، تو کہا: ’’بدذوق! کچھ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہوتیں، تم اپنا کام جاری رکھو!‘‘
اس طرح ایک دن فون کیا۔ اُس روز وہ بہت خوش تھیں۔ کہا کہ ’’بھائیوں کے ساتھ صلح ہوگئی ہے۔ امی بھی کئی دِن رہ کر گئی ہیں۔‘‘
یہ واقعی خوشی کی بات تھی اور اُس کے بعد مَیں مصروف ہوگیا۔ ایمن بھی شاید مصروف ہوگئیں۔
ایک دفعہ مَیں لاہور سے سوات آیا۔ ابھی فیملی لاہور شفٹ نہیں ہوئی تھی۔ مَیں گھر میں بچوں، بیوی اور ماں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ میں مشغول تھا۔ ایک نامعلوم نمبر سے فون آیا۔ دوسری طرف سے ایمن تھیں۔ اُنھوں نے کہا: ’’بدذوق! کہاں ہو؟‘‘
مَیں نے جواباً کہا: ’’سوات میں گھر ہی پہ ہوں!‘‘
پوچھا: ’’ گھر کا پتا کیا ہے؟‘‘
مَیں نے اُنھیں فون پر لنڈیکس کا پتا سمجھایا۔ دوسری طرف بیوی نے روتے روتے برا حال کیا۔ مَیں گھر سے نکل کر انتظار کرتا رہا۔ وہ آئیں۔ اَب کی بار زیادہ بااعتماد تھیں۔ گاڑی ٹیکسی تھی۔ ساتھ ایک گلوکار قسم کا بندہ اور ڈرائیور بھی تھے۔ کہا: ’’سوات آئے تھے، مگر فون ٹوٹ گیا تھا، اس لیے بدل دیا ہے۔ آپ کا نمبر بھی فون ہی کے ساتھ ضائع ہوگیا تھا۔ پیٹرول پمپ پر تلک راج نظر آیا، تو اُس کو آواز دی۔ آپ کے بارے میں پوچھا، تو اُس نے کہا کہ مَیں سوات آیا ہوں۔ آج ہی ملا ہوں۔ اُس سے نمبر لیا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔‘‘
ایمن شام دیر تک گھر پر رہیں۔ تب تک میری بیوی کی اچھی دوست بن گئی تھیں۔ وہ میری والدہ کو بہت اچھی لگیں۔ رخصت کرتے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا (سلائی کے بغیر) اسے دیا۔ میری بیوی نے بھی تحفے تحائف دیے۔ ایمن کو واپس پشاور پہنچنا تھا۔ نیا فون، اچھے کپڑے اور صحت مند صورت…… ایمن کے بچے بہ ضد تھے کہ یہاں رہ جائیں، یا مَیں اُن کے ساتھ چلوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔
وقت گزرتا چلا گیا۔ مَیں مصروف رہتا۔ رابطہ کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ ایک دن شام کو پشاور سے اسد کا فون آیا اور پوچھا سر اخبار پڑھتے ہیں؟ مَیں نے کہا، اخبار کی شکل دیکھے ہوئے بھی ہفتے ہوگئے ہیں۔ اُس نے کہا، ایک غم کی خبر ہے! مَیں نے ہنس کر کہا، کون سا اخبار ہے جس میں ہمارے غم چھپنے لگے ہیں؟ اُس نے جواباً کہا: ’’روزنامہ اوصاف، ایمن اُداسؔ کا قتل ہوگیا ہے۔‘‘
’’کب……!‘‘ مَیں بس اتنا ہی پوچھ پایا۔
’’کل اُس نے شادی کی تھی۔ وہیں دلہ زاک روڑ پر کہیں کسی فلیٹ میں تھیں۔ نئی دُلھن گھر پہ تھی۔ دولھا دودھ لینے مارکیٹ گیا تھا۔ دہشت گردوں نے آکر اُنھیں قتل کر دیا۔‘‘
یہ سننا تھا کہ مَیں دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ اُس نے ایک درخواست کی کہ سر اُس نمبر پر فون نہ کریں، جو آپ کے پاس ہوگا۔ یوفون کا نمبر تھا۔ ’’اور ہاں! مجھے آج اخبار سے پتا چلا ہے، سو آنے کا سوچنا بھی نہیں!‘‘
مَیں شاید ایمن کے نمبر پر رنگ دیتا، مگر اپنی بیوی کو فون کیا۔ وہ خاموش تھی۔ مَیں نے کہا، ایمن اُداسؔ کا قتل ہوگیا ہے۔ وہ بولی، ہاں! مگر ممی کَہ رہی تھیں کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ وہ میرے ساتھ رو پڑیں۔ مَیں اپنے دفتر کے واش روم میں گھس گیا اور چیخ چیخ کر رویا۔
سُمیّا اُس وڈیو میں تالیاں بجا رہی ہیں۔ امی کی کام یابی پر بہت خوش بھی تھیں۔ سمیا کی شادی چارسدہ میں ہوگئی۔ اُسامہ پشاور میں کہیں مزدوری کرتا ہے۔ ایمن کے قتل کے کچھ عرصے بعد اسد نے مجھے اُن کا نمبر ڈیلیٹ کرنے کا کہا اور اُسے ’’اندھا قتل‘‘ قرار دیا۔ پریس کے دباو میں ہر کسی کو شاملِ تفتیش کرنے کی بات کی۔ مَیں نے چہرہ دوسری طرف کیا اور اُس نے ایمن کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔
……………………………………
لفظونہ انتظامیہ کا لکھاری یا نیچے ہونے والی گفتگو سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اگر آپ بھی اپنی تحریر شائع کروانا چاہتے ہیں، تو اسے اپنی پاسپورٹ سائز تصویر، مکمل نام، فون نمبر، فیس بُک آئی ڈی اور اپنے مختصر تعارف کے ساتھ editorlafzuna@gmail.com یا amjadalisahaab@gmail.com پر اِی میل کر دیجیے۔ تحریر شائع کرنے کا فیصلہ ایڈیٹوریل بورڈ کرے گا۔

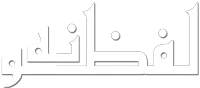





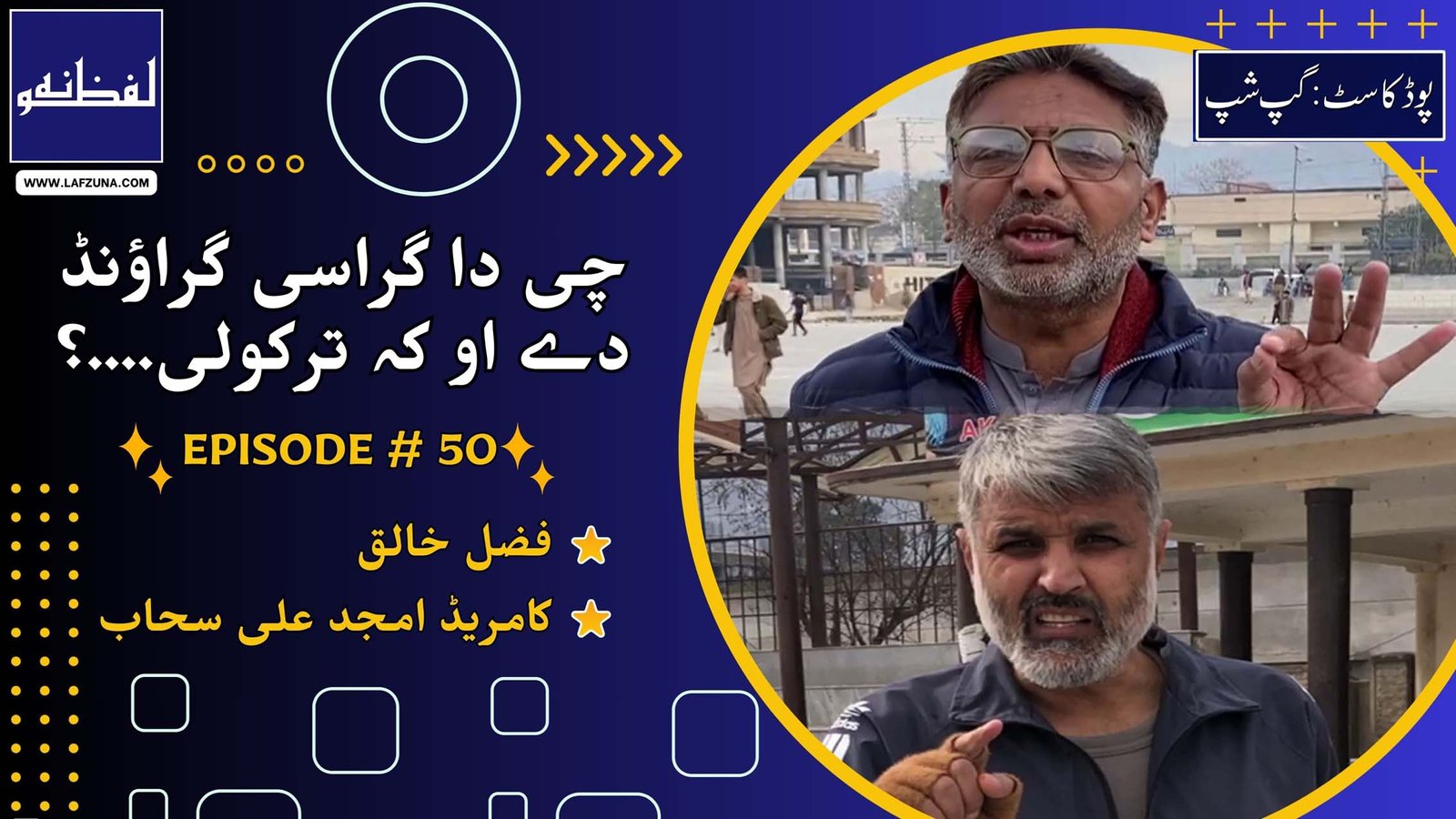



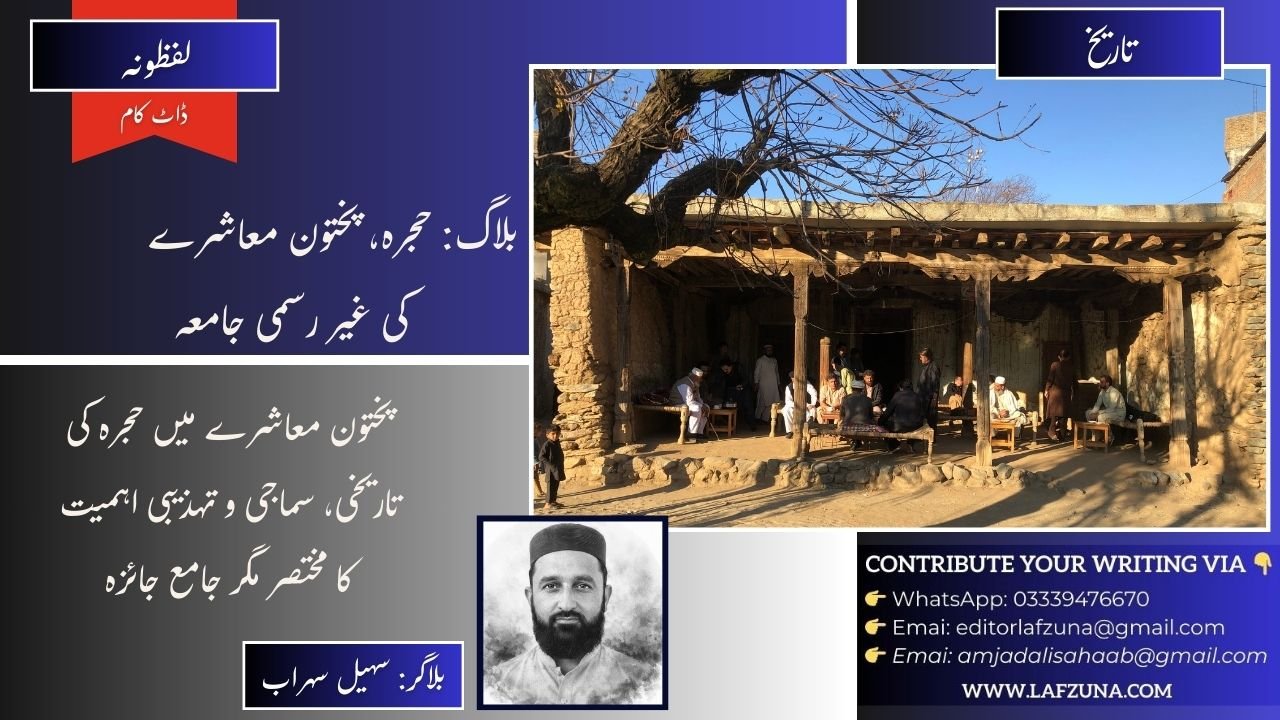

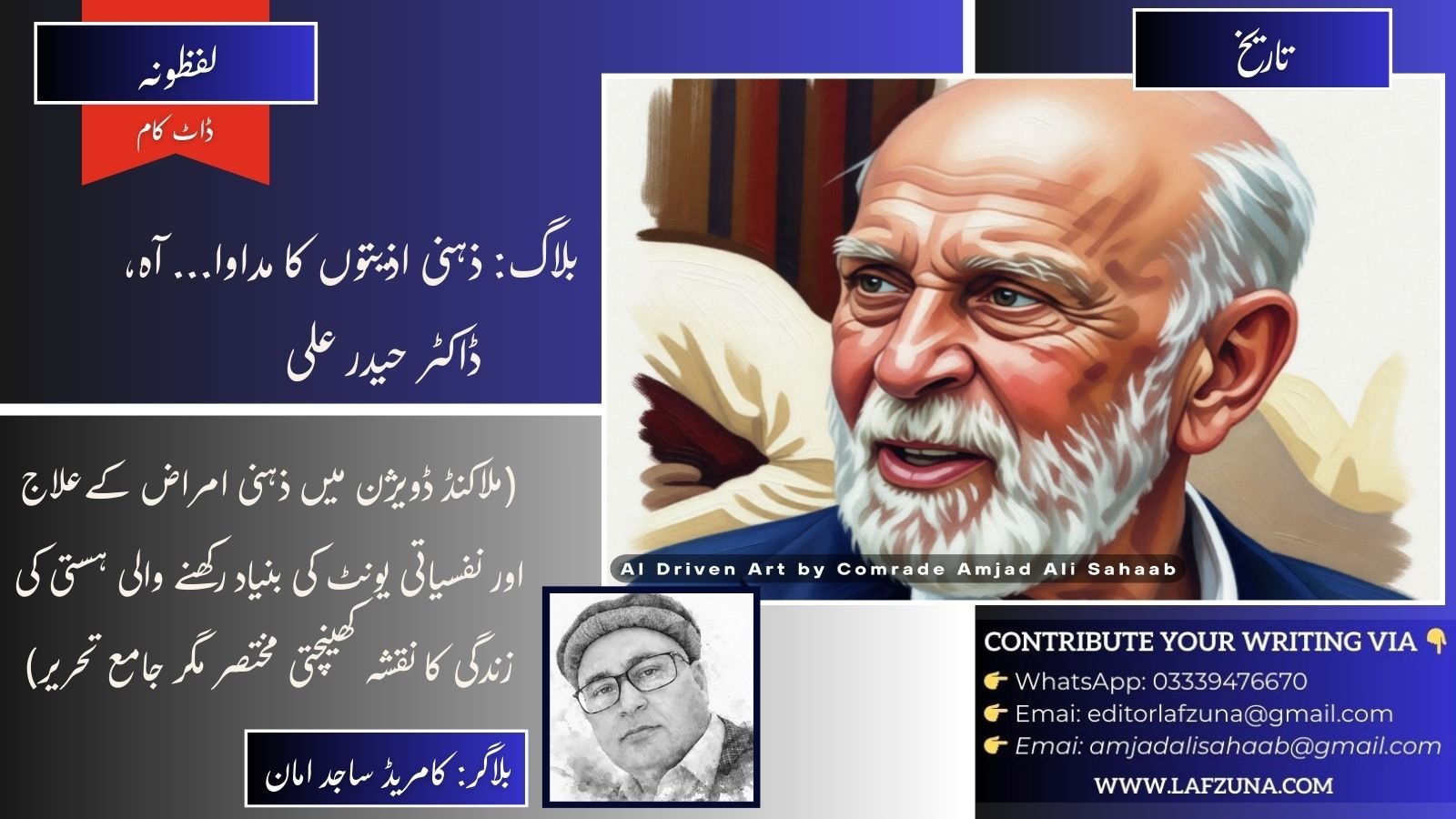
6 Responses
بہت عمدہ لکھا ہے۔ مجھے ایمن اداس کی موت کے بارے پہلی دفعہ پڑھنے کو مفصل مضمون ملا۔
اپنے وقت میں انہوں نے کچھ سپر ہیٹ گانے گائے جن کا اور گلوکاری کا زکر نہیں ہے اس مضمون میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریر اتنی دیر سے کیوں چھپی؟ کیا ابھی تک اس کے قتل کا معمہ معمہ ہی ہے؟
رحیم صابر صاحب
بہت شکریہ تبصرے کے لیے ۔
یہ لکھا تو عرصہ پہلے تھا مگر یہاں شائع اب ہوا ہے
بہترین تحریر۔
بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے
بہت شکریہ
یہ لکھا تو بہت پہلے تھا اور لفظونہ پر شائع بھی ہوا تھا ۔ لفظونہ نے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے میں مشکور ہوں